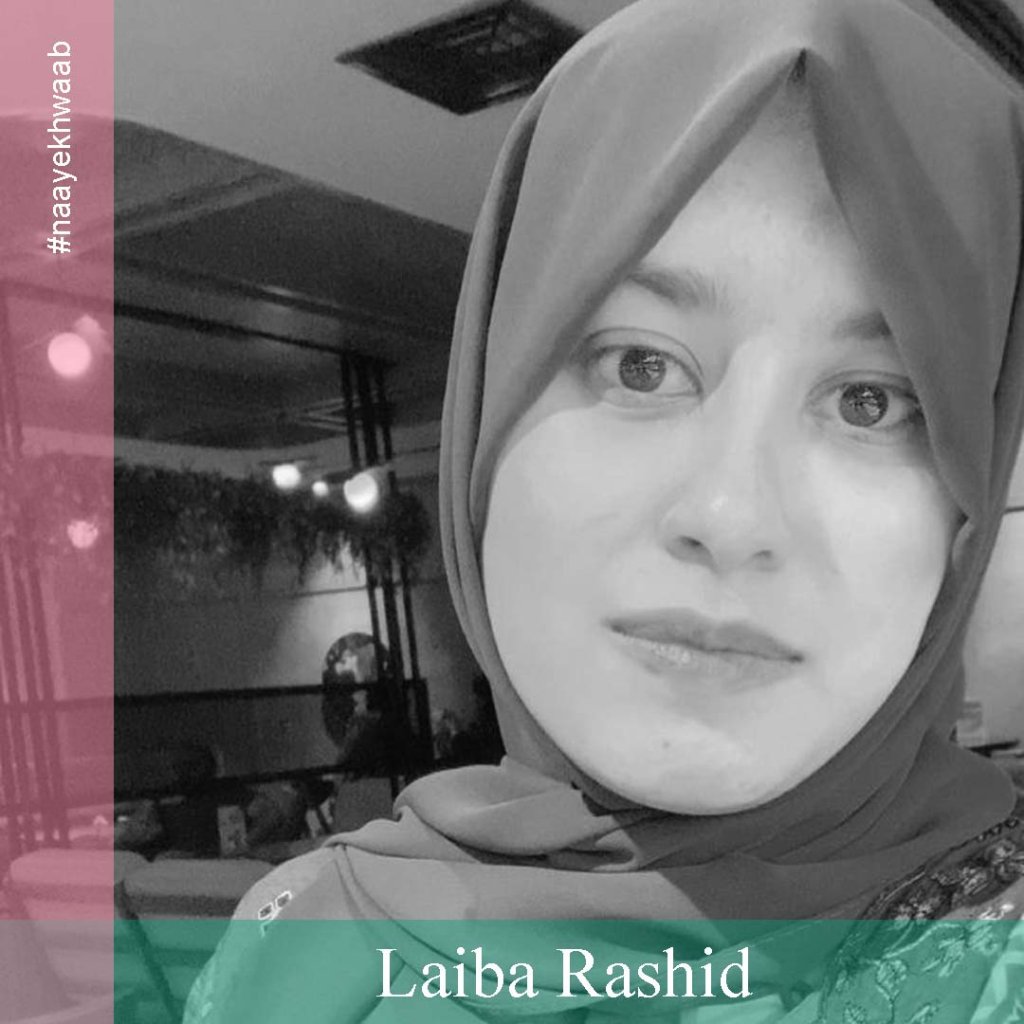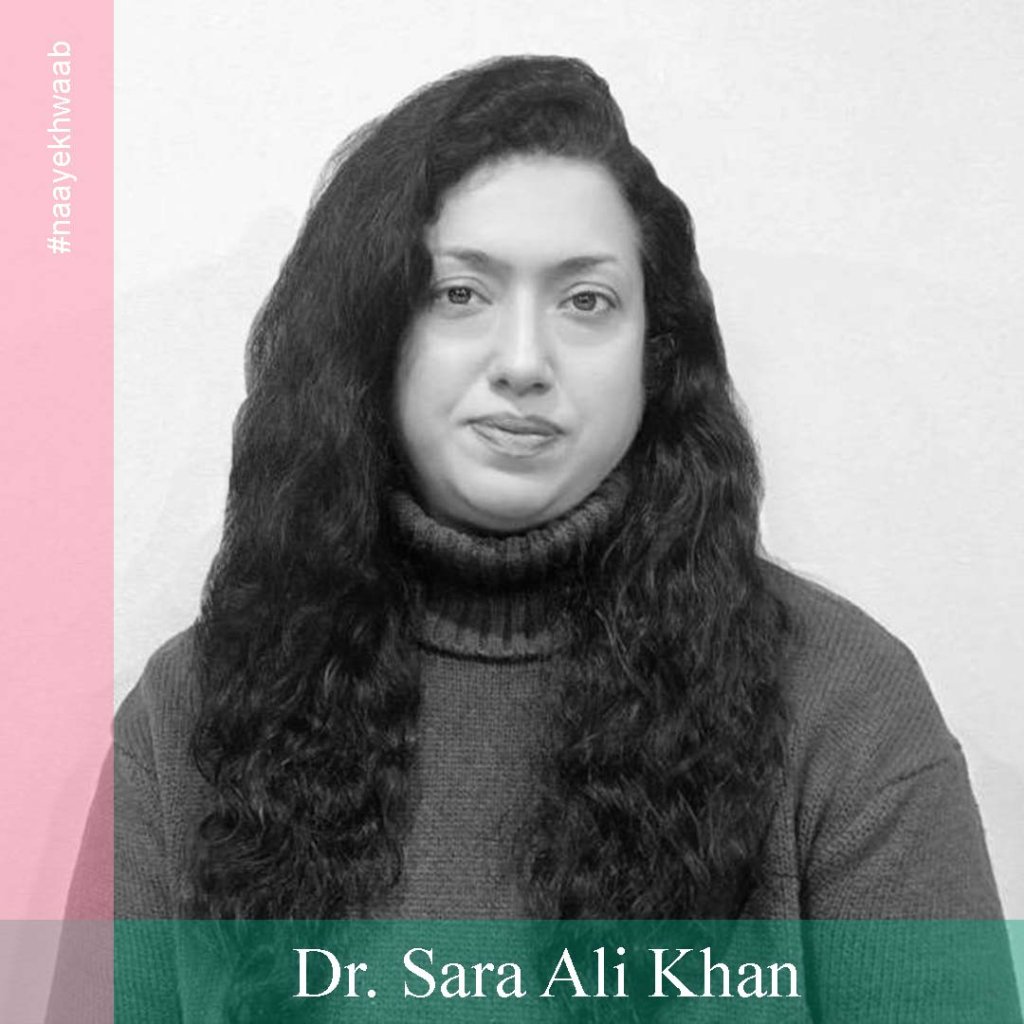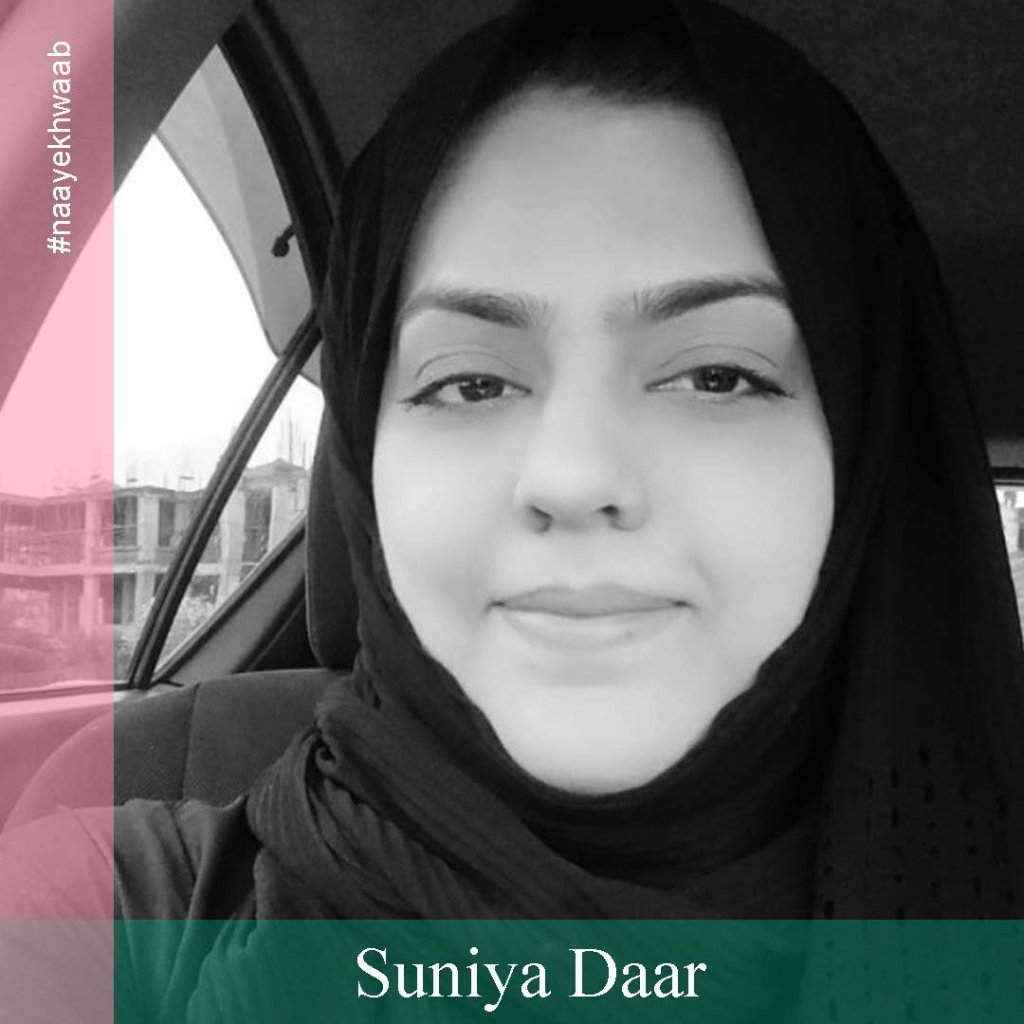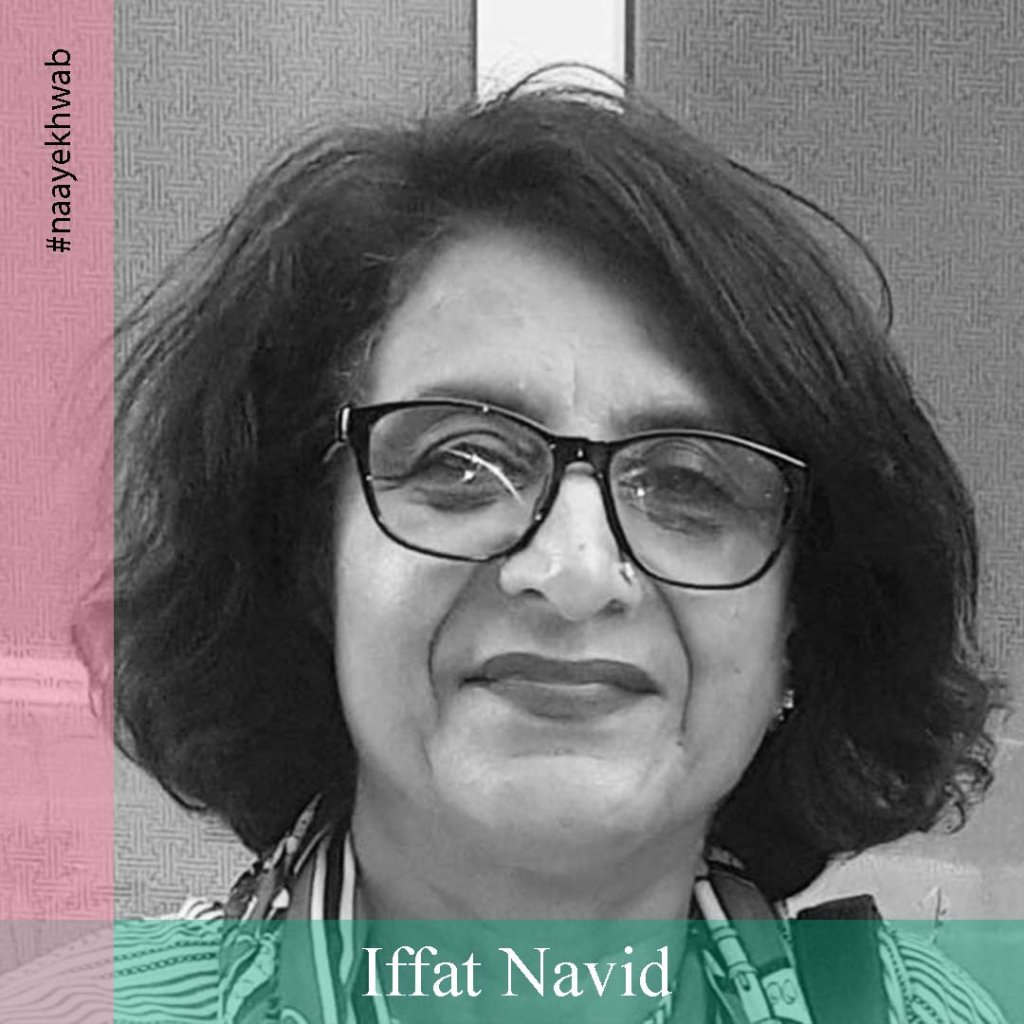From Hesitation To Healing: My Green Zone Therapy’s Expereince
From Hesitation To Healing: My Green Zone Therapy’s Experience Trying therapy for the first time through initiative of green zone therapy by Naaye Khwaab was an experience I never thought of.I had never entered a space that could really be non judgemental allowing you to speak your heart out and facing your fears. Upon an invitation by my friend Muqaddas, a Green Zone Trainer, I thought why not give it a chance and this chance changed my life. Attending the Green Zone Therapy Fellowship felt like entering a quiet, sacred space within myself—one I had long forgotten existed. It didn’t heal me overnight, nor did it promise to erase what life had carved into me. But slowly, gently, it began to open the stubborn doors I had shut tight—the ones guarding pain that never really belonged to me in the first place. The kind of pain that seeps in through other people’s wounds, the kind that makes you carry battles you were never meant to fight.The therapy helped me see how much of my suffering came from external forces—from people around me, their traumas, their pain, and the ripple effects of their actions. I had been holding onto a grudge for so long, not because I was the one who was hurt, but because someone I loved deeply had been hurt by someone else I also once held close. And in that tug of war, I was the rope—torn between resentment and empathy, hatred and softness. I found myself emotionally exhausted, confused, and stuck.Through the sessions, I was given the space to reflect deeply on the people in my life—who brings peace, who brings pain, and who simply doesn’t deserve the power to trigger my emotions anymore. I learned that it’s okay to step away from things that aren’t mine to fix. That just because I cared for both people involved didn’t mean I had to bleed for a war I never signed up for. I was never a mediator. I was a listener. And somehow, that role turned into a wound of its own.One of the most powerful moments for me was the letter-writing exercise. I poured into that paper every ounce of anger, sorrow, and the unsaid words I’d been carrying for years—things I could never say aloud, not even in the future. Because some bridges don’t just burn; they disappear. And while communication may solve many things, sometimes there’s no opportunity left to speak. So I wrote, not for closure with them, but for freedom within myself.Green Zone Therapy became the safe space where I could finally acknowledge what I’d been suppressing. It helped me realize that it’s not my job to solve other people’s conflicts. If two people are at odds—even if I love them both—it’s their path to navigate, not mine. I can hope they heal, I can wish them peace, but I cannot sacrifice my mental well-being in the name of loyalty.Healing, I’ve learned, isn’t a one-time event—it’s a choice I make every day. I train my thoughts like muscles, gently bringing them back to the path I’ve chosen when they wander into old wounds. I remind myself that I’m not carrying that grudge anymore. I’m not walking around with hate in my heart. Even if the thoughts come back sometimes—and they will—I now know how to let them pass without letting them stay.Green Zone Therapy didn’t just help me fix one trauma—it gave me the tools to live lighter, to love smarter, and to protect my peace without guilt. And for that, I am deeply, profoundly grateful. Leave a Reply Cancel Reply Logged in as admin. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*