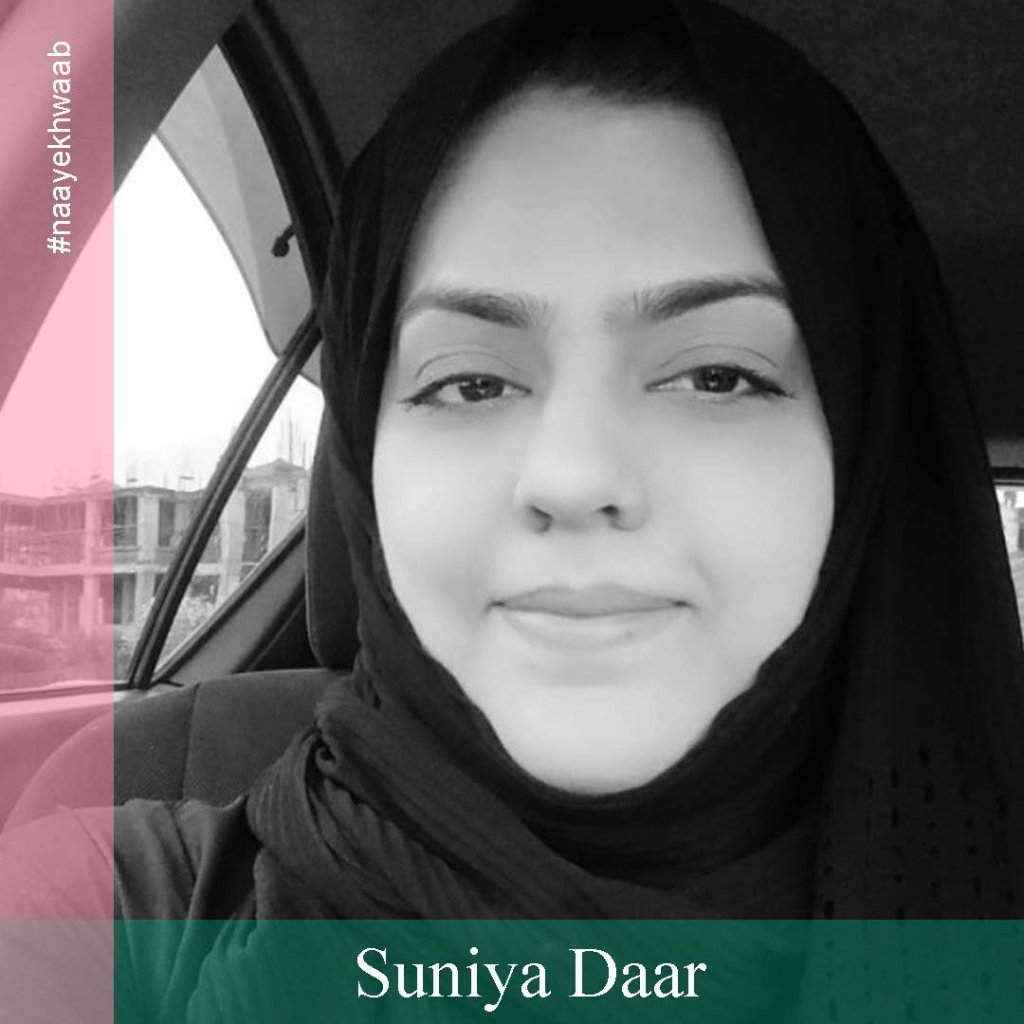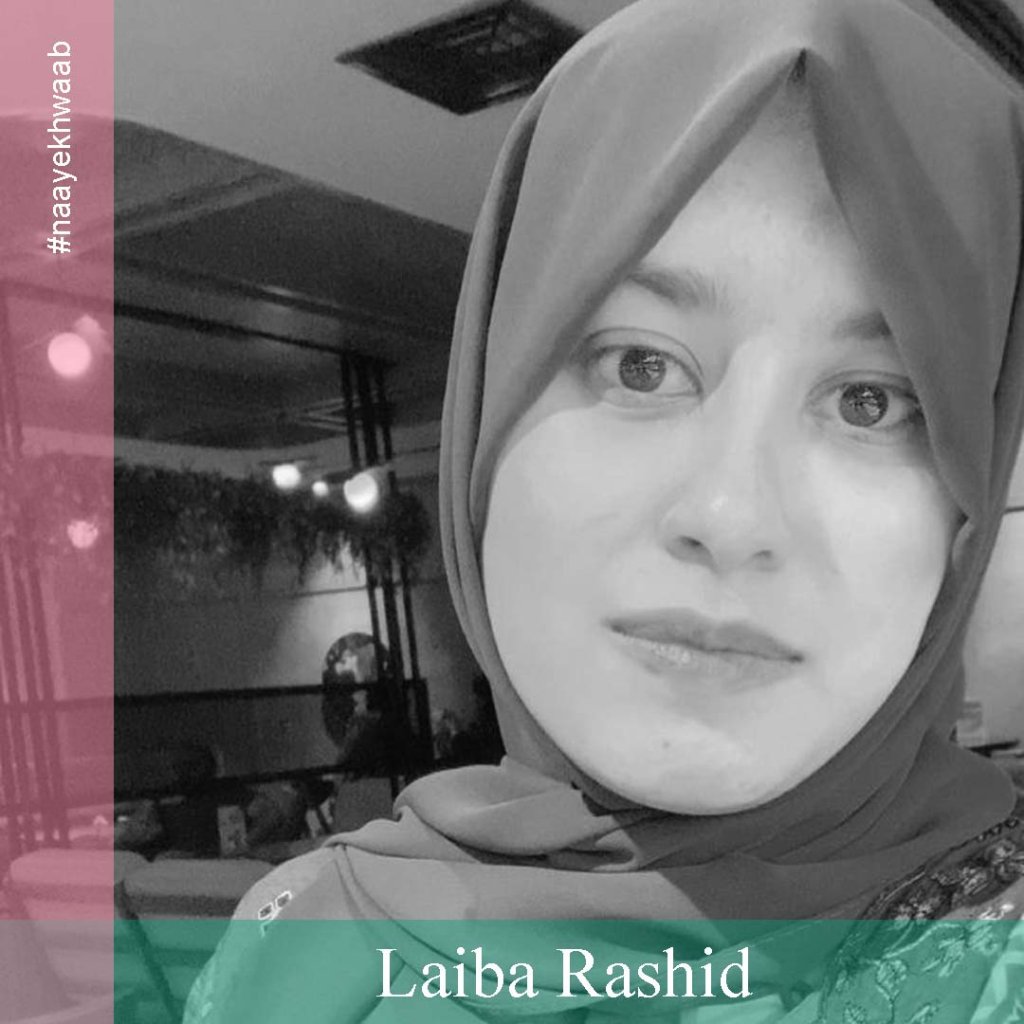نئے خواب، نیا نصاب”: مختصر تعارف و تبصرہ”
نئے خواب، نیا نصاب”: مختصر تعارف و تبصرہ” مقدس مجید صاحبہ سے میری پہلی ملاقات پاک ٹی ہاؤس میں ہوئی۔ ہم دونوں Urban World USA کے زیرِ اہتمام ہونے والے ایک پروگرام Pakistan Youth Poet Laureate کا حصہ تھے، اس لیے شاعری ہی ہمارے درمیان پہلا تعارف بنی۔ پہلی ملاقات میں ان سے ادب اور ادب کے علاوہ بہت سے موضوعات پر گفتگو کا موقع ملا، اور اس حوالے سے ان کے خیالات سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں عام طور پر لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کب کسی سے متاثر ہوا تھا۔ البتہ یہ بات میں مقدس مجید کے بارے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کی شخصیت اور ان کے خیالات سے بے حد متاثر ہوا۔ اسی ملاقات میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب “نئے خواب، نیا نصاب” بھی پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ یہ کتاب دراصل مقدس مجید اور معروف نفسیات دان ڈاکٹر خالد سہیل کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہے، جس میں کل 29 خط شامل ہیں۔ معاشرے کا شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ان خطوط کا موضوع نہ بنا ہو۔ سوال اٹھانے کی اہمیت سے لے کر عورتوں کے مسائل اور دیگر ایسے موضوعات، جنہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں taboo سمجھا جاتا ہے، ان خطوط کا حصہ ہیں۔ یہ کتاب دراصل نوجوان نسل کے مسائل پر ایک مکالمہ ہے، جن میں معاشرتی اور نفسیاتی ہر طرح کے مسائل شامل ہیں۔ یہ کتاب ایک فرد پر معاشرے کی لگائی گئی پابندیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کبھی بھی ایک فرد کو وہ نہیں بننے دیتا جو وہ بننا چاہتا ہے۔ نطشے نے کہا تھا: Society tames the wolf into a dog, and man is the most domesticated animal. ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ بچپن ہی سے اس کے سوالات پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور شاید سب سے زیادہ اسکول، کالج اور مدارس سے، جہاں کچھ بھی نیا سوچنے یا پوچھنے پر ستائش کے بجائے سزا ملتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تمام زندگی انہیں خیالات اور نظریات کے سہارے گزار دیتے ہیں جو ہمیں معاشرے اور خاندان سے ملتے ہیں۔ ہم کبھی ان پر سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی ان پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یا کیا یہ نظریات اور خیالات درست بھی ہیں یا نسل در نسل بغیر کسی شواہد کے منتقل ہو رہے ہیں؟ اس کتاب میں نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے مقدس مجید نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ آخر کامیابی کیا ہے؟ یہ سوال اکثر میں بھی سوچتا ہوں، اور یقیناً یہ سوال ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہوں گے۔ ڈاکٹر خالد سہیل اس حوالے سے بہت ہی عمدہ جواب دیتے ہیں کہ کامیابی مختلف لوگوں کے لیے مختلف تصور رکھتی ہے۔ کامیابی کی ایک تعریف وہ ہے جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے، یعنی پیسے کمانا، دنیاوی آسائشوں کے لیے جدوجہد کرنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا وغیرہ۔ جبکہ اس کے برعکس کامیابی کا ایک تصور غیر روایتی اور تخلیقی ہے، جس میں ایک فرد اس کامیابی کی اُس تعریف کو، جو اسے معاشرے کی طرف سے ملی ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاں کامیابی سچ کی تلاش اور اپنے اور دیگر انسانوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے — یعنی ادیب، سائنس دان، فلسفی وغیرہ۔ یہ بات بھی ایک معمہ ہے کہ معاشرے سے ملنے والے تصور پر عمل پیرا ہونے والے افراد صرف اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ جو معاشرے سے ہٹ کر اپنی کامیابی کا تصور خود تراشتے ہیں، وہ اپنی ذات کے بند کمرے سے نکل کر پورے معاشرے کے لیے سوچتے ہیں۔ اس کتاب میں ان مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے جو پدرسری معاشرے میں عورت کو پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی، بچوں کی ذمہ داری، نفسیاتی مسائل وغیرہ پر بھی بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، جس کو پڑھ کر ہمارے ذہنوں میں نئے نئے سوالات جنم لیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے قاری کو کس حد تک سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو کتاب آپ کے ان نظریات پر، جو کلیشے کی صورت اختیار کر چکے ہوں، سوال نہیں اٹھا سکتی یا آپ کو سوچنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی، وہ کتاب کامیاب نہیں کہلا سکتی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کتاب نہایت کامیاب ہے۔ ایسا معاشرہ، جہاں لوگ سوال نہیں اٹھاتے، یا جس میں لوگوں کی آنکھیں روایت سے ہٹ کر خواب نہیں دیکھتیں، وہ معاشرہ مشینوں کا معاشرہ ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے معاشرے میں مقدس مجید جیسی شخصیات موجود ہیں جو اس حوالے سے ہم نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہی ہیں اور تاریک شب میں چراغ کے مانند ہیں۔ اختتام پر پیرزادہ قاسم صاحب کا ایک شعر: میں ایسے فرد کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں (مہرعلی) Leave a Reply Cancel Reply Logged in as admin. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*